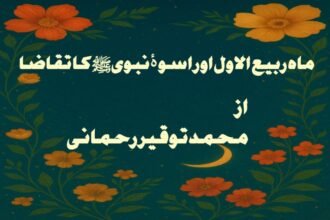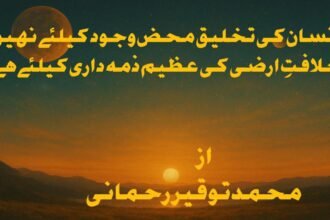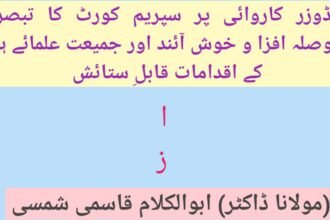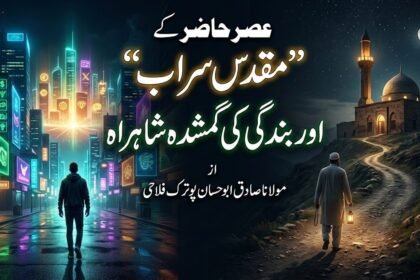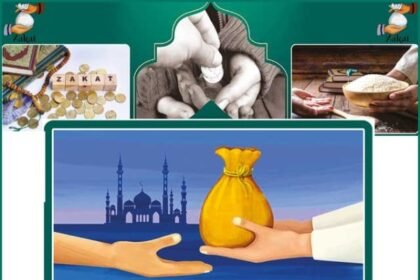احکام الٰہی کا مکلف انسان ہی کیوں؟
از__ محمد توقیر رحمانی
کائناتِ وجود ایک عظیم الشان کتاب کی مانند ہے، جس کا ہر ورق خالقِ کائنات کی قدرت اور حکمت کا زندہ شاہد ہے۔ سورج کا طلوع و غروب، زمین کا اپنے مدار میں بے خطا گردش کرنا، ستاروں کا شب کے پردے میں گوہرِ نور کی طرح جھلملانا، فضاؤں کا پُر سکون جمود، اور ذرّہ ذرّہ کا بے عیب نظام—یہ سب محض حسنِ ظاہری کے مظاہر نہیں، بلکہ عقلِ انسانی کو مجبور کرنے والے دلائل ہیں کہ اس کائنات کا ایک صاحبِ شعور اور لامحدود حکمت والا خالق موجود ہے۔
لیکن ایک سوال یہاں اپنی پوری سنجیدگی کے ساتھ اُبھرتا ہے: جب کائنات میں انسان کے سوا بے شمار مخلوقات موجود ہیں تو پھر تکلیف یعنی ذمہ داری اور جواب دہی کا بار صرف اور صرف انسان پر کیوں رکھا گیا؟
مخلوقات کی مراتب اور ادراک کی تقسیم
تمام مخلوقات کو، ان کے احساس، ادراک اور قوتِ ارادی کے درجے کے لحاظ سے تین بنیادی طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: جمادات، نباتات اور حیوانات۔
جمادات—پتھر، پہاڑ، دھاتیں یہ احساس اور ادراک سے بالکل خالی ہیں، اس لیے کسی قسم کی ذمہ داری یا تکلیف کے مکلف نہیں۔ ان کی اطاعت، ان کے وجود کی فطرت میں ہے، اور وہ اپنے رب کے حکم سے سرِ مو انحراف نہیں کرتے۔
نباتات—درخت، پودے، فصلیں یہ محدود احساس اور بنیادی حیات رکھتے ہیں۔ ان کی ذمہ داریاں صرف اپنے ارتقاء، بقا اور خوراک کے حصول تک محدود ہیں۔ حرکت کی آزادی نہ ہونے کے سبب خوراک کا نظام براہِ راست ان کے لیے زمین اور سورج کے ذریعے مہیا کر دیا گیا ہے۔
حیوانات—یہ نسبتاً زیادہ ادراک رکھتے ہیں، حرکت کی آزادی سے مزیّن ہیں، اس لیے ذمہ داریاں بھی کچھ زیادہ ہیں: خوراک کی تلاش، خطرات سے بچاؤ، اور نسل کی بقا۔ مگر ان سب کا دائرہ حیوانی جبلّت تک محدود ہے، وہ شعوری اخلاقی فیصلوں کے مکلف نہیں۔
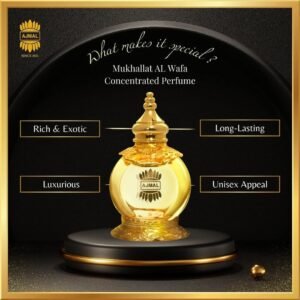
انسان کی خصوصیت: اکمل ادراک اور ارادہ
انسان اس سلسلے کی آخری اور سب سے ممتاز کڑی ہے۔ اسے صرف احساس نہیں، بلکہ مکمل ادراک عطا کیا گیا ہے۔ وہ نہ صرف یہ جانتا ہے کہ کیا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے پاس قوتِ ارادی ہے جو اسے محض ردِ عمل پر مبنی زندگی سے آزاد کر کے شعوری انتخاب اور اقدار کی پیروی کی صلاحیت دیتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ انسان پر ذمہ داری کا بوجھ بھی کامل رکھا گیا۔ قرآن نے اسی کو "تکلیف” کہا:
> لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
"اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔” (البقرۃ: 286)
قرآن نے اس تکلیف کو ایک اور نام دیا—امانت:
> إِنَّا عَرَضْنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَيۡنَ أَن يَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا (الأحزاب: 72)
یہ ایک نہایت عمیق اور حیرت انگیز منظرنامہ ہے: کائنات کے عظیم ترین مظاہر آسمان، زمین اور پہاڑ، جب اس امانت کے سامنے آئے تو لرز گئے، انکار کر دیا، کہ ہم اس کی ذمہ داری اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے۔ مگر انسان نے اسے قبول کر لیا۔
یہاں دو الفاظ "ظلوماً” اور "جہولاً” غور طلب ہیں۔
ظلم، عدل کا ضد ہے یعنی عملِ صالح سے انحراف۔
جہل، علم کا ضد ہے یعنی ایمان اور بصیرت سے محرومی۔
سورۂ عصر میں یہ دونوں کمیّاں واضح کی گئیں:
> "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ”—ایمان اور اعمالِ صالحہ کے بغیر انسان خسارے میں ہے۔
یہ تمام اوصاف—ادراک، احساس، قوتِ ارادی—کسبی ہیں، یعنی ان کا استعمال انسان کے شعوری اختیار پر منحصر ہے۔ یہی اختیار، یہی آزادی، اور یہی شعوری فیصلہ سازی کا حق، انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ مگر یہ شرف اپنے ساتھ ایک بھاری قیمت بھی لاتا ہے—جواب دہی۔
اگر انسان کے پاس یہ قوت نہ ہوتی تو ذمہ داری بھی نہ ہوتی۔ اگر ذمہ داری نہ ہوتی تو مقصدِ حیات کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ مگر چونکہ وہ جان سکتا ہے اور چن سکتا ہے، اس لیے اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا جانا اور کیا چنا۔
انسان کا مکلف ہونا محض ایک حکمِ شرعی نہیں بلکہ ایک منطقی و فطری تقاضا ہے۔ ادراک اور ارادہ کی تکمیل، خود بخود ذمہ داری کو لازم کر دیتی ہے۔ گویا مکلف ہونا انسان کی سب سے بڑی آزمائش بھی ہے اور سب سے بڑا شرف بھی۔ یہی امتحان، اسے حیوانی سطح سے بلند کر کے آسمانی پیغام کا امین بناتا ہے، اور یہی مقام اسے فرشتوں سے بھی آگے لے جا سکتا ہے یا پھر حیوانات سے بھی پست کر سکتا ہے۔
اگر انسان کو محض مکلف بنا دیا جاتا، تو اس کی عقل اپنی فطری جستجو اور تدبر کے ذریعے خالقِ کائنات کے وجود تک تو پہنچ سکتی تھی، مگر اس کا سفر ادھورا رہتا۔ وہ یہ تو جان لیتا کہ ایک رب ہے، مگر اس رب کی منشا کیا ہے؟ حیات کا اصل مقصد کیا ہے؟ صحیح و غلط کے قطعی معیارات کیا ہیں؟—یہ سب انسانی عقل اکیلے اپنی محدودیتوں کے باعث طے نہیں کر سکتی۔ اس لیے محض عقل پر بھروسہ کافی نہ تھا۔ ضروری تھا کہ انسان کے پاس ایک کامل اور محفوظ ضابطۂ حیات ہو، اور اس ضابطے کی نہ صرف زبانی تعلیم بلکہ ایک مجسم عملی نمونہ بھی موجود ہو، تاکہ وہ جان سکے کہ علم کو عمل میں کس طرح ڈھالا جاتا ہے۔

یہی وہ مرحلہ ہے جہاں وحی اور نبوت کی ضرورت ایک لازمی تقاضے کے طور پر سامنے آتی ہے۔ وحی آسمانی قانون کا خالص اور محفوظ ماخذ ہے، اور نبوت اس قانون کا زندہ مظہر۔ انبیاء نہ صرف اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں ان احکام کی عملی تعبیر بھی پیش کرتے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ "یہ قانون تو محض نظری ہے، اس پر عمل ممکن نہیں”۔ یوں اتمامِ حجت مکمل ہو جاتا ہے—انسان کو عقل عطا کر کے اس کے ذریعے خالق تک رسائی کا راستہ کھول دیا گیا، اور وحی و نبوت کے ذریعے مکمل ہدایت اور عملی مثال فراہم کر دی گئی۔ اب حجت باقی نہیں رہی؛ ہدایت بھی موجود ہے اور اس پر چلنے کا طریقہ بھی واضح ہے۔ اب نجات اسی پر کاربند رہنے میں ہے۔